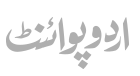اسلام آباد (اُردو پوائنٹ ۔ DW اردو۔ 12 اکتوبر 2025ء) ریاستوں کے قیام کے آغاز ہی سے حکمران طبقے کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ عوام کو کس طرح سے قابو میں رکھا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف سیاسی تجربات کیے گئے۔ بادشاہت کا قیام عمل میں آیا جو الٰہی قوتوں کا نمائندہ تھا اور تمام اختیارات کا مالک تھا۔ پھر اس میں یہ تبدیلی کی گئی کہ دو بادشاہ ہونے لگے تاکہ اختیارات تقسیم ہو جائیں اور ایک ہی بادشاہ متلق العنان نہ رہے۔
جب بادشاہی طرزِ حکومت اپنی ساکھ کھونے لگا تو اس کے متبادل کے طور پر اولیگارکی (Oligarchy) یا چند سری کا نظام قائم ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ اقتدار ایک فرد کے پاس نہ رہے اور چند افراد مل کر سیاسی نظام کو مستحکم کریں۔ رومی سلطنت میں جب ایٹروسکن (Etruscan) بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو اس کی جگہ Republican نظام قائم کیا گیا۔(جاری ہے)
ریاست کے تمام عہدیداروں کا انتخاب ہوتا تھا اور منتخب ہونے والے اراکین عوامی اسمبلیوں اور سینیٹ میں رعایا کی نمائندگی کرتے تھے۔
یونان
میں ریپبلکن کی جگہ ڈیموکریسی یا جمہوریت کا نظام قائم کیا گیا۔ لیکن یہ ایک محدود جمہوریت تھی۔ اس میں عورتوں غلاموں اور غیر ملکیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ عوامی اسمبلی سے سیاستدان خطاب کرتے تھے اور عوامی ووٹوں سے اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔تاریخ میں سیاسی نظام برابر بدلتا رہا۔ انگلستان میں 1250 عیسوی میں میگنا کارٹا کا قانون پاس ہوا۔
اس قانون کے تحت برطانوی پارلیمنٹ نے بادشاہ کے اختیارات کو کم کر دیا۔ اس کے بعد سے بادشاہ اور پارلیمنٹ میں برابر تصادم جاری رہا یہاں تک کہ 1688 میں پارلیمنٹ کافی حد تک با اختیار ہو گئی۔جب 1789 میں فرانس میں انقلاب آیا تو اس نے قومی ریاست کو قائم کیا۔ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ فرانسیسی انقلاب نے پورے یورپ کی سیاست کو بدل ڈالا۔
عوام جو اب تک خاموش تماشائی تھے انہوں نے اس کے بعد اپنے حقوق کے لیے مختلف گروہوں میں بٹ کر مزاحمت شروع کی۔ فرانس میں 1830 اور یورپ میں 1848 میں ان انقلابات نے یورپ کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ 1830 میں فرانس اور 1848 میں پورے یورپ میں انقلابی سرگرمیاں ہوئیں، جن کی وجہ سے عام لوگوں میں سیاسی شعور آیا۔نظام حکومت کے لیے دساتیر بنائے گئے۔ اسمبلیوں کے اراکین کے لیے انتخابات ہونے لگے۔
عوامی مظاہروں کی بھی ابتداء ہوئی۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے حکمراں طبقوں اور عام لوگوں میں فرق پیدا ہوا کیونکہ انتخابات میں عام لوگوں کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی تھی جو ابتداء میں محدود تھی مگر الیکشن جیتنے کے لیے عوام کے جذبات کو ابھارنا ضروری تھا۔ ان حالات میں امریکی صدر John Adam نے سب سے پہلے Tyranny of the Majority کی اصطلاح کو استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد John Stuart Mill نے اسی اصطلاح کو انگلستان کی سیاست میں روشناس کرایا تھا۔اب سوال یہ ہے کہ اکثریت کی آمریت کا جمہوریت اور سیاسی نظام سے کیا تعلق ہے۔ اکثریت کی کوئی ایک تاریخ ممکن نہیں ہے۔ یہ مختلف گروہوں پر مشتمل ہوتی ہے اور کوئی ایک نظریہ بھی اس سے ساتھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کا مجمع اچانک جمع ہو جاتا ہے اور پولیس اور فوج اسے فورا ہی منتشر کر دیتی ہے۔
عوام کی اکثریت کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی آمریت کو قائم کرے۔ درحقیقت آمرانہ طاقت اور اقتدار حکمران طبقے کی اقلیت کے پاس ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا ریاست پر قبضہ ہوتا ہے اس لیے یہ اپنی مراعات اور جائیدادوں کی حفاظت کے لیے نہ صرف ریاست کے اداروں کو استعمال کرتے ہیں بلکہ قوانین کے ذریعے لوگوں کی مزاحمت کو کچل دیتے ہیں۔ اپنے مخالفوں کو سزاؤں اور قید و بند کے حربے استعمال کر کے خاموش کر دیتے ہیں۔عوام کی اکثرت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنی تقریروں، نعروں کے ذریعے ان کے مذہبی سماجی اور معاشی جذبات کو ابھارتے ہیں۔ اب موجودہ دور میں عوام کو استعمال کرنے کا ایک ذریعہ دھرنے اور ہڑتال ہیں۔ جب سیاسی رہنماؤں کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو وہ عوام کو بھول جاتے ہیں۔
اس لیے یہ کہنا کہ اکثریت کا رویہ آمرانہ ہوتا ہے یہ کہہ کر سیاسی رہنما ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ آمرانہ طرز کے لیے جن اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے عوام کو وہ اختیارات کبھی نہیں دیے جاتے۔ انہیں ان مسائل میں الجھا کر رکھتے ہیں، جن کا فائدہ سیاسی رہنماؤں کو ہوتا ہے۔ سیاسی رہنما اپنی تقاریر میں عوام میں غصے اور جوش کو پیدا کر کے انہیں عمارتوں کو توڑ پھوڑ کرنے اور دکانوں کو آگ لگانے میں مصروف کر کے اپنے مقاصد توحاصل کر لیتے ہیں مگر عوام کے بارے میں یہ تاثر ابھرتاہے کہ یہ جاہل، غیر مہذب اور امن و امان کے دشمن ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں بنیادی حقوق دیے جائیں اور ان کا سماجی رتبہ بڑھایا جائے۔
لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی سیاسی نظام ہو اس میں حکمراں طبقہ آمریت کے ذریعے اپنا تحفظ کرتا ہے اور لوگوں کو جذباتی بنا کر ان کا سیاسی اور سماجی استحصال کرتا ہے۔نوٹ: ڈی ڈبلیو اردو کے کسی بھی بلاگ، تبصرے یا کالم میں ظاہر کی گئی رائے مصنف یا مصنفہ کی ذاتی رائے ہوتی ہے، جس سے متفق ہونا ڈی ڈبلیو کے لیے قطعاﹰ ضروری نہیں ہے۔