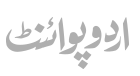سائنس اور مذہب کا پیداکردہ اختلاف
جمعہ 25 دسمبر 2020

قاضی فضل اللہ
1۔ایک مذہب سے
2۔ اور دوسرا معیشت سے
اور جب مذہب اور معیشت کا مقابلہ آجاتا ہے تو مذہب شکست کھا جاتا ہے۔ یعنی انسان مذہب کو یا اسکی تعلیمات کو پسِ پشت ڈال کر معیشت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ترجیح عموماً تو عمل کے حد تک ہوتی ہے یعنی مذہب کا تقاضا ایک ہوتا ہے لیکن معیشت کیلئے وہ بندہ اس کا ضدعمل اختیار کرجاتاہے مثلاً مذہب کہتا ہے چوری حرام ہے لیکن ایک بندہ چوری کرجاتا ہے ۔یعنی مذہب کا حکم ایک جانب رکھ دیتا ہے۔ مذہب کہتا ہے جھوٹ نہ بولو ،دھوکہ نہ کرو، خیانت نہ کرو لیکن ایک بندہ معیشت کیلئے یہ سب کچھ کرجاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ عمل عقیدے تک بھی چلا جاتا ہے تو ایک بندہ مال اور معیشت کیلئے مذہب تبدیل کرجاتا ہے ۔
(جاری ہے)
کئی ایک مذاہب کے مشنریز مفلوک الحال علاقوں میں کچھ فلاحی کام کرکےیا کچھ غریبوں کو کھلاکے ان کی مذہب تبدیل کرواتے ہیں اور یہ کام زیادہ تر عیسائی یا پھر قادیانی کرتےہیں۔
جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے ان کا تو چونکہ مذہب قومی ہے یعنی بنی اسرائیل کیلئے ہے لہذا وہ اس قسم کی مشزیز نہیں چلاتے ۔ان کے ہاں تو ایک صحیح یہودی ہونےکے لیے ماں کا یہودی ہونا ضروری ہے ماں اگر یہودی نہ ہو باپ اگر چہ یہودی ہو لیکن اس کا بچہ صحیح یہودی اور بنی اسرائیلی تصور نہیں ہوتا۔ کئی ایک علاقوں میں تو ان کے مقبرے بھی علیحدہ ہوتے ہیں۔ ہاں ساتھی اور سپورٹرز کی تو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے صہیونی اور فری میسن تحریکات ہیں جن میں غیر اسرائیلی لیکن صاحب حیثیت وثروت لوگ ممبرز بنتے ہیں۔ ان کے لیے ان تحریکات کا سپورٹ لازمی ہے مذہب کی کوئی قید نہیں اور کئی ایک کو تو ان کے خفیہ منصوبوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ و ہ تو اپرکلاس کلب کا ممبر بننے کے لیے یہ سب کچھ کرجاتا ہے لیکن اس کے پیسے ان منصوبوں پرچلے جاتے ہیں ۔اب یہ تو ایک انسانی مخمصہ ہے جس میں انسان پہلے دن سے پھنسا ہوا ہے ۔ بہت ہی کم ایسےہونگے جو عقیدے اور عمل پر کوئی سودابازی نہیں کرتے چاہے وہ بھوکے مرجائیں لیکن یہ تو راسخ العقیدہ اور صالح العمل لوگ ہوتے ہیں ۔
دنیا ارتقائی ہے اور یوں انسان کو نئے نئے چیلنجز کا سامناہوتا ہے۔آج کا دورسائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ اس سے معیشت کا استحکام ہے یعنی یہ معیشت کا انجن بن چکا ہے تو آج کی دو بڑی حقیقتیں ہیں۔
1۔ ایک مذہب
2۔اور دوسری سائنس اور ٹیکنالوجی
أساساً طبیعیات وکیمیا اور دیگر سائنس مضامین کے حوالے سے مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے اور وہ سائنس دان چونکہ دینی علوم کے بھی حاملین تھے لہذا اس دور میں تو کبھی کسی نے یہ سنا بھی نہیں تھا کہ سائنس اور مذہب آپس میں ایک دوسری کے مخالف ہیں ۔لیکن اسے مسلمانوں بلکہ انسانوں کی بدقسمتی سمجھئے کہ وہی علم جب یورپ والوں نے وہاں سے سیکھا اور اس کا یورپ میں اظہارکیا تو کلیسا اور چرچ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور چونکہ اس وقت کے حکمران اور حکومت کلیسا اور اس کے نمائندوں کو خدا کا نمائندہ سمجھ کر ان کے ہر بات کو حتمی اور واجب العمل قرار دیتے تھے لہذا ان سائنس دانوں کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زندہ جلا دیا گیا، انہیں زہر کے پیالے دیے گئے ان کو دیگر اذیت ناک سزائیں دی اور یوں ایک تصور پیدا ہوا کہ سائنس اور مذہب آپس میں رقیب،حریف،دشمن اور مخالف ہیں اور ایک تصور جب اس قسم کے واقعات کو بھی بغل میں لیاہوا ہو وہ کسی نہ کسی صورت زندہ رہتا ہے۔
بعد میں ایک دوسری بد بختی یہ ہوئی کہ اب ریاست چونکہ ایجادات دیکھ رہی تھی اور اسے قبول بھی کررہی تھی لیکن چرچ کے ساتھ کیا کیا جائے۔سو اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ چرچ اور ریاست کوعلیحدہ کیا جائے کہ اجتماعیت میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا ۔ بعد ازاں زیادہ ترممالک برطانیہ فرانس، اٹلی اور سپین کی کالونیاں رہیں اور انہیں ممالک میں سائنس دانوں کو اذیت ناک موت مروایاگیا تھا اور انہی مما لک نے ریاست اور چرچ کوعلیحدہ کیا لہذا وہ جہاں بھی رہے قوت میں رہے اور جوقوت رکھتے ہوں ان کی فکر رائج ہوجاتی ہے۔ سو یہ فکرتمام کالونیز میں جوتقریباًساری دنیا تھی میں رائج ہوگئی ۔
اور تیسری بد قسمتی یہ ہوئی کہ دو قسم کے نصابِ تعلیم رائج ہوئےخصوصاً مسلم ممالک میں ایک کو دینی اور قدیم کہاگیا اور دوسرے کو عصری اور جدید کا نام دیاگیا ۔یعنی حصول علم کے حوالے سے دو طبقے پیدا ہوئے اور ہر دو ایک دوسرے کو رقابت کی نظروں سے دیکھنے لگے اور یوں نہ صرف یہ کہ خلیج پیدا ہوگیا بلکہ مذہبی اداروں والے ان عصری اداروں والوں کو کافی حد تک گمراہ تصور کرتے رہے ہیں۔جبکہ عصری اداروں والے ان دینی اداروں والوں کو دقیانوسی، گنواراور ناسمجھ گردانتے ہیں ۔اب عصری اداروں والے تو دعوت کے مقام پر نہیں لیکن دینی اداروں والے تو دعوت کے مقام پر ہیں یعنی ان کا تو کام ہے لوگوں کو دین کے اندرلانا، دین کے ساتھ ان کو لگانا۔
اب ٹیکنالوجی تو ایک امرہے اور امر ہوچکی ہے اس کو آپ رد تو نہیں کرسکتے یہ تو چلےگی اور یہ تو ٹیکنالوجی ہے جس میں فی نفسہ ٖکوئی خرابی نہیں خرابی تو اس کے استعمال کی ہوسکتی ہے لیکن اس کا اچھااستعمال بھی تو ہے۔ لیکن بہت سارے مذہبی لوگ اس کےاصل کی مخالفت شروع کرتے ہیں بلکہ عصری اداروں تک کی مخالفت اور حصول تعلیم کے مخالف ہوجاتے ہیں جبکہ وہ خود بھی ان اداروں کی پیدا کردہ ٹیکنالوجی کو جنون کی حد تک استعمال کرتے ہیں خصوصاً انٹرنیٹ ،ٹیلی فون،موبائل فون، کمپیوٹر، واٹس ایپ ،فیس بک ،یوٹیوب وغیرہ وغیرہ۔اس ٹیکنالوجی کے موٹرسائیکلزپرسواری کرتے ہیں۔ اب یہی موٹر سائیکل چوری کے لیے بھی استعمال ہوسکتا ہے، قتل کے لیے بھی اور خدانخواستہ بم بلاسٹ کےلیے بھی جس سے بیسیوں بے گناہ ہلاک ہوسکتے ہیں تو کیا موٹرسائیکل بنانا بند کرنا ہے؟
جیسا ہم نے کہا کہ معیشت اور عقیدہ ومذہب کا مقابلہ ہو تو عقیدہ و مذہب شکست کھائیگا کیونکہ انسان ضروریات قربان نہیں کرسکتا پھر تومر جائیگا اور کون ہے جو مرنے کےلیے تیار ہوگا۔
اسی طرح ہم اپنی ناسمجھی سے مذہب کو ٹیکنالوجی کے مقابلہ پر لائیں گے تو مذہب شکست کھائے گا کہ اب تو ٹیکنالوجی مسلط ہوچکی ہے اور ضرورت بن چکی ہے ۔ایسے میں تو ٹیکنالوجی ماننے والے لا دین ہوجائیں گے تو کیا ہم نے عزم کیا ہے کہ لوگوں کو لادین کریں گے؟ اور مذہب کو شکست دلائیں گے حالانکہ یہ دین تو
لیظھرہ علے الدین کلہ
اور
ویکون الدین للہ
کے لیے ہے۔ تومسئلہ دین میں نہیں ہمارے میں ہے جو دین کی غلط تشریح یا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نہیں سمجھتے تو کہیں میں نہیں جانتا اس میں کیا شرم اور عار ہے ۔
اب اس مسئلے کے حل کے دو طریقے ہیں۔
1۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگ پیداکیے جائیں جو بیک وقت ہر دو قسم کے علوم کے ماہر اگر نہ بھی ہوں تو ایک کا ماہر ہو لیکن دوسرے سے بھی مکمل نابلد نہ ہو بلکہ اسے بھی ایک خاطر خواہ حد تک جانتا ہو۔ایک اچھا مسلمان بننے کیلئے دین کا مناسب علم ضروری ہےاور اچھا انسان بننے کیلئے ہر علم سے کچھ نہ کچھ حاصل کرناچاہیئے تاکہ بندہ اضطراب ،اختلاف اور جہالت کی تہمت سے بچے ۔
2۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ماہر تو کسی ایک کا بنے لیکن ہر دو علوم کے ماہرین کا ایک دوسرے سے نہ صرف تعلق ہو بلکہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا کہ ایک دوسرے کے علم کے أساسیات اور مبادی تو سمجھیں اور یوں ایک دوسرےکو بھی سمجھ پائیں گے۔
لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے علمی اور تعلیمی اداروں کا معیار بہت پست ہوچکاہے اور دوسرے کے علم کا تو کیا خود ہی اپنے میدان کے علم پر بصیرت نہیں اس پر بھی مطمئن نہیں ۔ کیونکہ ان اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے اس حد تک کہ بس پڑھائی کی جاتی ہے۔ جبکہ آج کا دور تحقیق اور تخلیق کا ہے ۔ اور یہ موقوف ہے تفہیم اور تجزیہ پر کہ استاد صرف تعلیم نہ دے بلکہ وہ اسکی تفہیم کرائے ،طالب علم کو سنے بلکہ از خوداس سےکہہ دے کہ پوچھوکیا پوچھنا چاہتے ہو۔اگر ایسا موقع نہ دیا جائے تو طالب علم کا انفعال نہیں بیدار ہوتا۔ استاد سائیس ہے یہ سدھانے والا ہوتا ہے ۔ اس میں سکھانے کا تڑپ ہونا چاہئے اور یہ تب ہوسکتا ہے جب اس کو اپنے مضمون پر عبور ہو،وہ اس کے مسائل کا تجزیہ کرسکتا ہو، وہ اس کے مسائل پر خود سوال کرے اور پھر جواب دے۔ اس انداز سے سکھائے تو خود اس میں استاد کا بھی فائدہ ہے کہ اس کا اپنا علم پختہ بھی ہوتا رہتا ہے، اس میں وسعت بھی آتی ہے۔ لیکن اس کے لیے تجسس پیدا کرنا ضروری ہے اور تجسس بھی ایسا کہ اسے سکھانے کا جنون چڑھ جائے پھر اس کے سامنے بیٹھنے والے شاگر د ذہناً حاضر ہوتے ہیں ۔ اس قسم کا استاد اپنے شاگردوں کے لیے قائد بن جاتا ہے وہ پھر اس کا نقل اتارتے ہیں کہ استاد سےان کی عقیدت پیدا ہوجاتی ہے ۔
یہ جنون کب پیدا ہوتا ہے؟
جب مطالعہ وسیع اور عمیق اور ایک تسلسل سے ہو۔ایسے میں ایک جانب سے احترام اور دوسرے جانب سے شفقت پیدا ہو تا ہے ۔ فعل و انفعال کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے بالکل ویسا جیسا کہ ایک ماں اور دو دھ پیتے بچے کے درمیاں ہو کہ یہاں بچے کی چاہت پیدا ہوتی ہے اور وہاں ماں کی چھاتی انگڑائی لیتی ہے ۔یہ ایک ریموٹ یا غیرمرئی ربط ہوتا ہے اساساً تو سارے انسانوں میں ہے کہ ایک ہی ایٹم سے تو سارے پیدا ہوئے ہیں البتہ اس ربط کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ ایک اچھی ماں بچے کو نہ صرف یہ کہ دودھ پلاتی ہے بلکہ وہ خود اپنے خوراک کا خاص خیال رکھتی ہے اپنے لیے نہیں بچے کے لیے کہ مقوی خوراک سے دودھ پیدا ہو تو بچے کے لیے مفید اور نافع ہے۔ اس طرح استاد کی فطرت بھی جب ماں والی بن جائے تو وہ بھی شاگر دوں کے خیر کے لیے عمیق مطالعہ کرتا رہتا ہے ۔
تو آج کادور ٹیکنالوجی کا ہے ۔ اس کے لیے تعلیم، تجزیہ، تحقیق، تجربہ اور تخلیق ان مدارج کو ایک ساتھ چلانا ہوگا ۔عصری علوم میں اور قدیم علوم میں بھی تعلیم، تجزیہ اور تحقیق تو ہوتاہے بایں معنی کہ ان ایجادات کے حوالے سےنت نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ یکدم کہا جائے چھوڑو یہ گمراہی ہے۔ اس سےتو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایسے میں تو جدید دور کے لوگوں کو ہم دین سے برگشتہ کروا رہے ہیں جس پر گرفت ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت ذہن میں نہیں آرہا تو کہوکہ میں ذرا اس پر تحقیق کرکے پھر جواب دوں گا ۔خود بھی تحقیق کرو ورنہ جن کا اپروچ ہے ان سے رابطہ کرو کہ یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔
ہم روزانہ ترقی ترقی کا راگ الاپ رہے ہیں۔ ترقی صرف معاشی نہیں ہوتی یہ سماجی اور معاشرتی بھی ہوتی ہے۔ سماج اور معاشرہ کی ترقی کے لیے اقدار، اخلاق اورآداب جتنی اہمیت رکھتے ہیں تعلیم بھی اتنی بلکہ زیادہ اہم ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ معاشرہ کے لیے اخلاق و اقدارا ور آداب اگر رسمی تعلیم سے لاتعلق لوگوں میں بھی ہوں تو یہ تعلیم اور وہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ تعلیم یافتہ کا معنی صرف پڑھالکھا نہیں ہوتا اور صرف پڑھنے لکھنے کا نام بھی تعلیم نہیں ۔ تعلیم ایک شعبہ ہے اور کسی بھی شعبے کی اصل اس کے اقدار کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اب تعلیم کے اقدار صرف معلومات منتقل کرنا نہیں بلکہ تفہیم، ادراک ،تجزیہ، تحقیق اور تخلیق ہیں تاکہ تنقیدی سوچ اور تحقیقی مہارت پیدا ہو۔ اس سےصحیح فہم و ادراک آجاتا ہے اور اس علم کو بندہ اپلائی کرسکتا ہے ورنہ پھر تورٹا ہوگا اوررٹا تو طوطا بھی لگالیتا ہے لیکن اس کو اس کا فہم و ادراک تو نہیں ہوتا۔
اب یہ کیسے ہوگا؟
اس کے لیے سوچ کی آزادی، اظہاررائے اور بیان کی آزادی اور انتخاب یعنی چوائس کی آزادی چاہیے ہوتی ہے ۔ یعنی اساتذہ کی تربیت ایسی ہو کہ وہ طالب علم کے لیےقائد ثابت ہو کہ اسے چلا سکے ۔ نصاب تو صحیح ہے وہ پڑھائے گا لیکن وہ طالب علم کوغیر نصابی اور غیر رسمی انداز سے بھی پڑھانے کی مہارت رکھتا ہو۔ اس سے تعلیم اور تعلم دونوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے ۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عصری تعلیمات میں بھی واضح جدائی پیدا کی ہے کہ ایک طرف نیچرل سائنسز جس میں فزیکل سائنسز اور بائیولاجیکل سائنسز شامل ہیں اور ان کو فی الجملہ سائنس سبجیکٹس کا نام دیا جاتا ہے یہ ایک علیحدہ میدان ہے۔اور سوشل سائنسز جس کو ہیومن سائنسز یا ہیومنٹیز کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ میدان ہے۔ وہ دینی اور عصری علوم کا خلیج تو ایک طرف یہ ایک دوسرا خلیج ہے جو عصری علوم میں موجود ہے ۔
یہ صحیح ہے کہ آج معاشی ترقی نیچرل سائنسز پر موقوف ہے لیکن معاشرتی ترقی کے بغیر معاشی ترقی ادھوری ہے اور معاشرتی ترقی تو ہیومن سائنسز سےآتی ہے۔لہذا نیچرل سائنسز والوں کو بھی ہیومن سائنسز کا ایک خاطر خواہ حصہ پڑھانا ضروری ہے اور ہیومن سائنسز والوں کو بھی نیچرل سائنسز کا ضروری حصہ پڑھانا ضروری ہے وگر نہ اس طرح مختلف طبقات وجود میں آتے رہیں گے۔ اب ہیومن سائنسز والے تو نیچرل سائنسز والوں کی ایجادات وغیرہ سے عملی استفادہ توکرتے رہیں گے یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ان کا فکری لحاظ سے تو کوئی اپروچ نہیں ہوگا لیکن عملی تو ہے جبکہ نیچرل سائنسز والے تو ہیومن سائنسز کو درخور اعتناء نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے؟ سو شیالوجی کا کیا کرناہے؟ اور یوں ان میں انفرادیت پسندی پیدا ہوگی جو کہ فطرت انسانی کے خلاف ہے ۔اور نیچرل سائنسز والوں کو ہیومن سائنسز یعنی سوشل سائنسز کا کچھ نہ کچھ ادراک ہو تو یوں وہ معاشرے سے جڑے رہیں گے اور معاشرہ میں تو مذہبی علوم کے حاملین بھی ہوتے ہیں ان سے بھی میل میلاپ ہوتا رہےگا یوں وہ مذہب اور اس کے حاملین سے نہیں بدکیں گے اور مذہب والے ان سے نفرت نہیں کریں گے اور میل ملاپ سے باہمدگر بات چیت سے وہ ایک دوسرے کے علم و فن کو بھی کم از کم اس حد تک تو سمجھ پائیں گے کہ سائنس اور مذہب میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ دونوں کا میدان ہی الگ الگ ہے اور ہر دو سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے کہ سائنس دنیوی زندگی کو آسان بناتا ہے اور مذہب دنیا میں رہنے اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔
ادارہ اردوپوائنٹ کا کالم نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔
تازہ ترین کالمز :
قاضی فضل اللہ کے کالمز
-
توہین رسالت کے مسئلے کو آئی سی جے اور یواین اومیں لے جایا جائے
منگل 26 جنوری 2021
-
صحیح سوچ اور پھر صحیح عمل
جمعہ 22 جنوری 2021
-
اتحاد مطلوب ہےمگرکیسے؟
جمعہ 15 جنوری 2021
-
"ادخلواالارض المقدسۃ"
ہفتہ 9 جنوری 2021
-
سماجی بنو تاکہ انسان بن سکو
منگل 5 جنوری 2021
-
زندگی جہد مسلسل کا نام ہے
ہفتہ 2 جنوری 2021
-
سائنس اور مذہب کا پیداکردہ اختلاف
جمعہ 25 دسمبر 2020
-
نامردنہیں مرد بنائیں
منگل 22 دسمبر 2020
قاضی فضل اللہ کے مزید کالمز
کالم نگار
مزید عنوان
UrduPoint Network is the largest independent digital media house from Pakistan, catering the needs of its users since year 1997. We provide breaking news, Pakistani news, International news, Business news, Sports news, Urdu news and Live Urdu News
© 1997-2025, UrduPoint Network
All rights of the publication are reserved by UrduPoint.com. Reproduction without proper consent is not allowed.